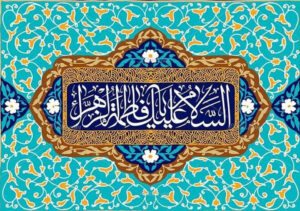تحریر:محمد حسین چمن آبادی
مومن عربی زبان کا لفظ "آمَنَ "سے اسم فاعل ہے۔ یہ لفظ اپنے مشتقات سمیت ۲۳۱ دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے البتہ ان سب آیات میں ایمان سے مراد صرف اعتقاد قلبی نہیں بلکہ تسلیم کے ساتھ اطمینان قلبی ہے کیونکہ فرعون کی قوم کا اعتقاد ثابت تھا کہ جو حضرت موسی ؑ پر اترتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے لیکن دل سے ان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔پس مومن وہ شخص ہےجو حق کے سامنے سر تسلیم خم ہو اور اس کے ساتھ اعتقاد بھی رکھتا ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ہم اس مختصر مقالے میں مومن کی سماجی خصوصیات بیان کریں گے۔
1۔ایماندار
قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک ایسا امر ہے کہ جس کی بناء پر خود خدانے انسان سے عہد لیا ہے کہ وحدہ لاشریک کے سوا کسی کے سامنے تسلیم نہ ہوں۔اگر انسان میں ایمان کا رمق بھی موجود ہو تو کسی بھی کام میں اس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایمان وہ صفت ہے جو انسان کو دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی راہ میں سدّ سکندری بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔امیر المومنینؑ نے مومن کی چار علامات بیان کی ہیں۔(الْإِيمَانِ أَنْ تُؤثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُك وَأَلاَّ يَكُونَ فِي حَديِثِكَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِكَ وَأَنْ تَتَّقِيَ اللهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ)( نہج البلاغہ،حکمت ۴۵۵)۔ « ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے سچائی باعث نقصان ہو، اسے جھوٹ پر ترجیح دو، خواہ وہ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے ہو»۔
دوسری جگہ آپؑ ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:( الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ)« ایمان چار ستونوں پر قائم ہے:صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر آپؑ نے ہر ایک کی چار چار شاخیں بیان کی ہیں» ( نہج البلاغہ،حکمت 30) ۔2۔انسان دوست
آج کل دنیا میں انسانی دوستی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ انسانی حقوق اور حقوق نسواں کی باتیں ہورہی ہیں لیکن مولائے کائنات نے چودہ سو سال پہلے تہذیب وتمدن سے عاری قوم میں انسان دوستی کی ایسی مثال قائم کی ہیں کہ آج تک کوئی بھی دوسرا اس پایہ تک نہیں پہنچ سکا۔آپؑ نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر مقرر کرتے ہوئے ایک نوشتہ دیا اس کا ایک جملہ یہاں ذکر کروں گا کہ علیؑ کی انسان دوستی کی مثال نہیں مل سکی۔آپؑ نے فرمایا:(وَلاَتَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ:إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ) (نہج البلاغہ، مكتوب 52)۔« رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو؛ اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا »۔
آپؑ نے حضرت امام حسنؑ کے نام لکھے گئے خط میں بھی انسان دوستی کی بہترین معیار بیان کیا ہے:ياﺑﻨﻲ،ﺍﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻴﺰﺍﻧﺎً ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻙ ،ﻓﺄﺣﺒﺐ ﻟﻐﻴﺮﻙ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ ،ﻭﺍﻛﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻩ ﻟﻬﺎ،ﻭلا ﺗﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ لا ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﺗُﻈﻠﻢ،ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﻳُﺤﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ۔ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﺤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻙ،ﻭﺍﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ۔ﻭلا ﺗﻘﻞ ﻣﺎ لا ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻗﻞَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ،ﻭلا ﺗﻘﻞ ﻣﺎ لا ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻚ(نہج البلاغہ،مکتوب 31 )۔«اے فرزند!اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یونہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یونہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویہ کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ اگرچہ تمہارے معلومات کم ہوں دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے ہو»۔3۔عدالت خواہ
عدالت ایک ایسی صفت ہے جس کے حصول کے لیے انبیاء اور آئمہ ؑ اور دیگر الہٰی نمائندے آتے رہے۔عدل کی جو تعریف مولا علیؑ نے نہج البلاغہ میں کی ہے اس سے جامع کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی: اَلْعَدْلُ یَضَعُ الاْمُورَ مَوَاضِعَهَا «عدل تمام امور کو ان کے موقع اور محل پر رکھتا ہے»( نہج البلاغہ، حکمت، ٤٣٧)۔
امیر المومنینؑ کی عدالت خواہی کے بارے میں عیسائی مصنف جارج جرداق کا معروف جملہ ہے:« علیؑ عدالت کے اجراء میں شدّت کی وجہ سے قتل ہوئے» دنیا میں آج تک جتنے بھی حکمران قتل ہوئے یا تخت حکومت سے اتارا گیا ہے سب میں ایک چیز مشترک تھی وہ ان کا ظلم اور عدم مساوات، لیکن دنیا کا واحد حکمران جسے اس کی عدالت خواہی کی وجہ سے شہید کیا وہ امیر المومنین علیؑ ہیں۔4۔حسن ظن کا عادی
مومن کی سماجی خصوصیات میں سے ایک دوسرے انسان کی نسبت اس کا حسن ظن رکھنا ہے۔اگر ہمارے معاشرے میں بد نیتی جیسی اخلاقی رزائل کی جگہ اعتماد اور حسن ظن لے لیں تو بہت سارے مشکلات خودبخود ختم ہو سکتی ہیں۔
امیر المومنینؑ نے اپنی بیوی کےمتعلق حسن ظن رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا: وإِيّاك والتّغايُرَ في موضع غَيرةٍ، فَإنَّ ذلك يدعُو الصّحيحةَ إلى السّقيمَ، والبريئَةَ إلى الرّيب(نہج البلاغہ،مکتوب 31)«بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاکباز عورت بھی بے راہی اور بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے »۔
حسن ظن کب تک ہم پر واجب ہے اور کس وقت یہ بے کار ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی مولا علیؑ نے بیان فرمایا ہے: إذا استَولى الفسادُ على الزّمان وَأهله،فأَحسنَ رجُلٌ الظنَّ بِرَجُلٍ فَقَد غَرَّرَ(نہج البلاغہ،مکتوب،۳۱)«جب دنیا اور اہل دنیا پر شر وفساد کا غلبہ ہو اور پھر کوئی شخص دوسرے سے حسن ظن رکھے تو اس نے ( خود کو ) خطرے میں ڈالا»۔5۔اتحادو اتفاق کا خوگر
اتحاد ووحدت انسانی معاشرے کی اہم ترین اکائیوں میں سے ایک ہے۔ افراد کے درمیان اتحاد سے لیکر مذاہب و ادیان کے درمیان ہم آہنگی کسی بھی سماج کے امن و سکون کا ضامن ہوتی ہے۔امیر المؤمنینؑ امام وحدت ہے اور اسی اعتبار سے آپؑ نے نہج البلاغہ کے مختلف مقامات پرمعاشرے کے اکائیوں کے درمیان اتفاق پر زور دیتے ہوئے فرمایا:وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ (نہج البلاغہ، خطبہ 127)« تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق واتحاد رکٖھنے والوں پر ہے اور تفرقہ وانتشار سے باز آجاؤ اس لیے کہ جماعت سے الگ ہوجانے والا شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑئیے کو مل جاتی ہے» ۔
امام المتقین ؑاتحاد واتفاق کو اللہ ورسول ؐ کی راہ اور اختلاف وانتشار کو شیطان کی راہ قرار دیتے ہوئے فرماتےہیں: إِنَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ؛ ، فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ (نہج البلاغہ،خطبہ 119)«بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈالوائے ۔ تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو»۔6۔عفیف وپاکدامن
عفت وپاکدامنی انسان کا زیور ہے۔ دین اسلام نے عفت کی حفاظت اور ناشائستہ اعمال و گفتار سے پر ہیز کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ امیر المؤمنینؑ نے عفت وپاکدامنی کو متقین کی بہترین صفت قرار دی ہے:أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ(نہج البلاغہ،خطبہ ۱۹۵ )۔« نفس، نفسانی خواہشوں سے بری ہیں»۔
مولائے کائنات نے عفت کی کئی قسمیں بیان کی ہیں جیسے گفتار، پیٹ، لباس اور جمال وغیرہ کی عفت۔ہم یہاں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف عفت شکم کے بارے میں مولا ؑ کے کلام کو نقل کریں گے۔
کھانے پینے میں عفت کا مطلب ہے خورد ونوش میں اعتدال برقرار رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل نرم، ارادہ قوی، خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے ساتھ عبادات ومناجات میں لذت محسوس کرتا ہے۔ امام علیؑ نے کوفہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ، وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ؛ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ [وَجْهِهِ] وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ( نہج البلاغہ، مکتوب ۴۵) «اے ابن حنیف! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کےعمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جارہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جارہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرلوگے جن کے یہاں سے فقر ونادار دھتکارے گئے ہوں، اور دولت مند ہوں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چٖھوڑ دیا کرو اور جس کے پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ»۔7۔امر بالمعروف ونہی عن المنکر
مومن ہمیشہ گناہگار شخص کو شیطان اور نفس امارہ کے چنگل سے نجات دلانے کا سوچتا ہے۔ اس کی خیر خواہی چاہتا ہے اسیب لیے معروف اور نیک کاموں کی طرف دعوت اور معصیت و نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر المؤمنینؑ نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت و ضرورت اور فوائد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہیں۔ امام نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاء(نہج البلاغہ،کلمات قصار ۲۵۲)«امر بالمعروف اصلاح خلائق کے لیے اور نہیں عن المنکر کو سر پھروں کی روک تھام کے لیے عائد کیا»۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت برتنے کے انجام کے بارے میں آپؑ فرماتے ہیں:لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم ( نہج البلاغہ، مکتوب ۴۵)«نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہوجائیں گے پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی»۔
مولائے کائنات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے ڈرنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں:وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ (نہج البلاغہ،خطبہ 154)«نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آسکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کمی ہوسکتی ہے»۔
امام نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ترک کرنے والوں کی عاقبت سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا :فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَر ( نہج البلاغۃ، خطبہ ۱۹۲)«خداوند عالم نے گذشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے»۔8۔شکر گزار
مومن ہمیشہ اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکرگزار رہتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔مولائے متقیان علی بن ابی طالب ؑ نے شکر گزاری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ ( نہج البلاغہ،کلمات قصار 135)«جو شکر کرئے وہ اضافہ سے محروم نہیں ہوتا»۔
مومن کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کو علم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ شکرکے ساتھ نہیں کیا جاسکتا:الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ، نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ وَ نَيِّرِ بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ؛ حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً ( نہج البلاغہ،خطبہ ۱۸۱)« تمام حمد اس کے لیے ہے جس کی طرف مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے۔ ہم اس کے عظیم احسان، روشن وواضح برہان اور اس کے لطف و کرم کی افزائش پر اس کی حمد وثناء کرتے ہیں۔ ایسی حمد کہ اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو اور اس کے ثواب کے قریب لے جانے والی اور اس کے بخششوں کو بڑھانے والی ہو»۔
امیر المؤمنین ؑ شکر گزاری کو نعمتوں کے اضافے کا ضامن قرار دریتے ہوئے فرماتے ہیں: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ، وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ( کلمات قصار،434 )« ایسا نہیں کہ اللہ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور (نعمتوں کی) افزائش کا دروازہ بند كر دے»۔9۔صابر
مومن کی اہم خصوصیات میں سے ایک صبر وبردباری ہے۔سختی اور دشواریوں سے سامنا انسانی زندگی کا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ان مشکلات سے مقابلہ کرنا اور سختیوں کو جھیلنا اور پریشانیوں کے مقابلے میں استقامت دکھانے سے انسان کی زندگی شیریں بن جاتی ہے۔ اگر صبر واستقامت کی نعمت سے بے بہرہ ہوں تو انسان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ اسی لئےامیر المؤمنینؑ نے صبرکو نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے:رحم الله امرأ سمع حُكما فوعى،… و جَعل الصبر مطية نجاته ( نہج البلاغہ،خطبہ۷)«خدا اس شخص پر رحم کرے، جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا۔۔۔ اور صبر کو نجات کی سواری بنا لیا»۔
صبر کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں مولا متقیان ؑ نے فرمایا:فى وصيته لابنه الحسن عليه السلام: عوّد نفسك التصبّر على المكروه، و نعم الخُلق التصبُر فى الحق ( نہج البلاغہ،مکتوب 31)«سختیوں کو جھیلنے کا خوگر بنو۔حق کی راہ میں صبر وشکیبائی بہترین سیرت ہے»۔مولا علیؑ نے صبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے انسانی سر کے ساتھ تشبیہ دی ہے:عليكم بالصبر؛ فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، و لا خير فى جسد لا رأس معه، و لا خیر فى ايمان لا صبر معه( نہج البلاغہ،مکتوب، 42)« صبر وشکیبائی اختیار کرو کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ اگر سر نہ ہو تو بدن بےکار ہے یونہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں ۔ ہر وہ شخص جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان بھی نہیں»۔10۔امانتدار
امانتداری ایک ایسی صفت ہے جس کے ہوتے ہوئے بہت ساری مشکلات حل اور معاشرہ پر امن ہوتا ہے۔ اسی لیےقرآن و حدیث میں امانتداری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ امیر المؤمنینؑ نے امانتداری کا پہلا درجہ یہ بیان فرمایا کہ خدا کی امانت کا محافظ ہوتا ہے:لا يضيع ما استحفظ ( نہج البلاغہ، کلمات قصار،174)« پرہیرگار کبھی اللہ تعالی کی طرف سے اس کے سپرد شدہ چیزوں کو ضائع نہیں کرتا»۔امانتداری کی ضد خیانت ہے۔ اشیاء کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے ، اسی فارمولے کے لحاظ سے امیر المومنینؑ نے خیانت کی شدید مذمت کی ہے:مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّة( نہج البلاغہ،مکتوب ۲۶)۔«یاد رکھو! جو شخص امانت کو بے وقعت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دےاور خیانت کی چراگاہوں میں چرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے، تو اس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتوں اور خواریوں میں ڈالا، اور آخرت میں بھی رسوا وذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے»۔مولائے متقیان ؑ نے امانتداری میں سستی کو خیانت کی بدترین قسم قرار دی ہے:مِنْ أَفْحَشِ الْخِيانَةِ خِيانَةُ الْوَدائِعِ( نہج البلاغہ،كلمات قصار، ۶)۔«بد ترین خیانت ، امانت میں خیانت ہے»۔
مومن کی سماجی خصوصیات جو نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنینؑ نے بیان فرمایا ہے،ان سب کو بیان کرنا ہمارے اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہےاگر چہ بعض چیدہ چیدہ خصوصیات کا ذکر کیا ہےاور کچھ کو بغیر تفصیل ذکر کریں گے کیونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہیں۔ ان صفات پر مفصل لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صفات اور خصوصیات پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں جیسے موت سے نہ ڈرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا، امتحان الہٰی کے آگے تسلیم خم ہونا، زیرکی اور ہوشیاری، استقامت وپائیداری، خوش اخلاقی، عزت ووقار، تواضع وفروتنی، سخاوت مندی، عاقل ہونا، یتیم نوازی، دوسروں کے ساتھ تسامح سے پیش آنا، خدا پر توکل کرنا، سچائی کا خوگر ہونا، دنیا سے بے رغبتی اور ان جیسی دیگر سینکڑوں صفات کہ جن کو مولاؑ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے ہر ایک کو سنہرے حروف میں لکھ کر زندگی میں اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی کرنا ضروری ہے۔