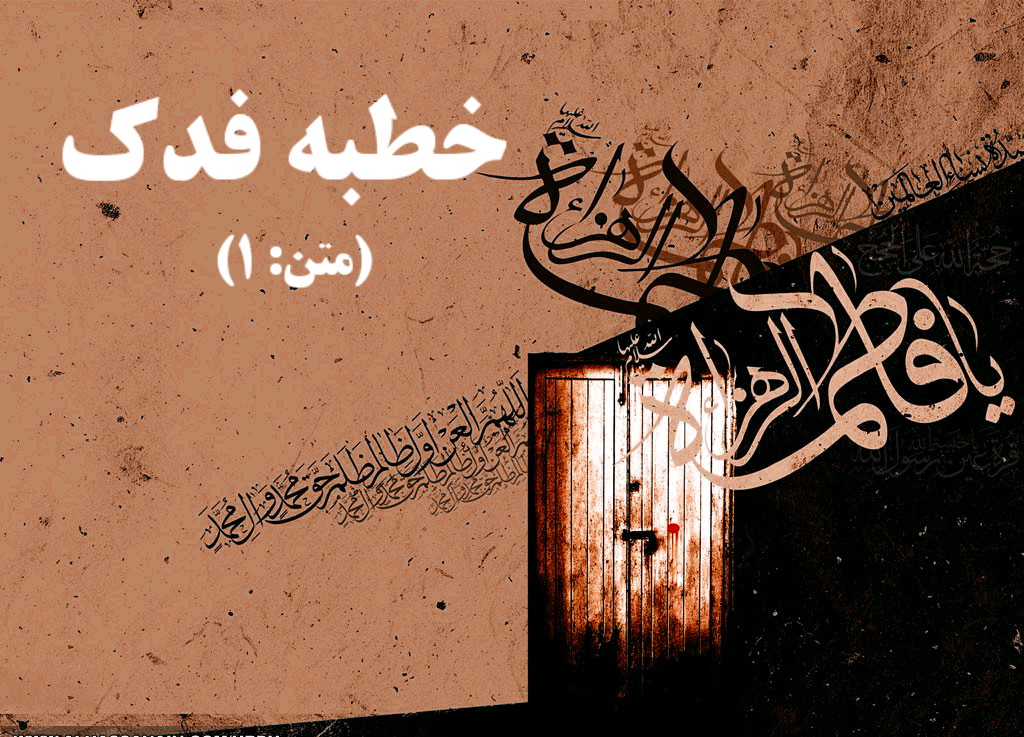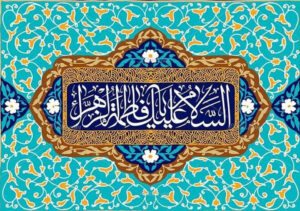حضرت فاطمۃ الزہراء علیہا السلام کا خطبۂ فدک
خطبہ-فدک-متن1
حضرت فاطمۃ الزہراء علیہا السلام کا خطبۂ فد
بسم اللہ الرحمن الرحیم
بنام خدائے رحمن رحیم
اَلْحَمْدُلِلَّهِ عَلی ما اَنْعَمَ، ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائیں۔
وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلی ما اَلْهَمَ،اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے (اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے) عنایت کی ہے۔ (۱)
وَ الثَّناءُ بِما قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ اِبْتَدَاَها،اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہیں۔ (۲)
۱۔علی ما الہم: الہام انسان کے نفس کے اندر ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس طاقت کو حجت باطنی کہتے ہیں نیز اسے عقل اور وجدان بھی کہا جاتا ہے ۔ کبھی ہم اسے ضمیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ انسانی ضمیر میں اللہ تعالی نے خیر و شر، پاکیزگی و پلیدی، فسق و فجور اور تقوی کا ادراک اور فہم دویعت فرما دی ہے۔ اسی لئے یہ نفس اچھائی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے کی آواز پہچان لیتا ہے اور اسے پذیرائی ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَ نَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰىہَا ﴿﴾ فَاَلۡہَمَہَا فُجُوۡرَہَا وَ تَقۡوٰىہَا
(شمس ؍۷۔۸۔)
اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا پھراس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ عطا فرمائی
۲۔وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سوال کے بغیر از خود عنایت فرماتا ہے ۔ دعائے رجبیہ میں آیا ہے:
یا من یعطیہ من لم یسئلہ ومن لم یعرفہ
اے وہ ذات جو اسے بھی عنایت فرماتا ہے جس نے نہ سوال کیا، نہ اس نے پہچان لیا۔
وَ سُبُوغِ الاءٍ اَسْداها،
ان ہمہ گیر نعمتوں پر جن کے عطا کر نے میں اس نے پہل کی۔(۳)
وَ تَمامِ مِنَنٍ اَوْلاها،
اور ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی۔ـ
جَمَّ عَنِ الْاِحْصاءِ عَدَدُها،
اور یہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں(۴)
وَ نَأى عَنِ الْجَزاءِ اَمَدُها،
اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے(۵)
وَ تَفاوَتَ عَنِ الْاِدْراکِ اَبَدُها،
اور (انسان)ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ (۶)
تشریح کلمات
سبوغ :
فراوان۔
جم :
زیاد ۔
نأی:
دور ۔
ندب :
پکارا ۔ دعوت دی ۔
۳۔ وہ نعمتیں جو تمام انسانوں کیلئے یکساں طور پر عنایت فرماتا ہے۔
۴۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا :
وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوھا (سورہ النحل آیت ۱۸)
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔
۵۔جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنا یقینا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کسی محدود عمل سے لامحدود نعمتوں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔
۶۔بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کی گہرائی اور ان کی انتہائی حدود انسان کے احاطۂ ادراک میں نہیں آسکتیں۔ بہت سی نعمتوں سے آج کا انسان آشنا ہے مگر کل کے انسان آشنا نہ تھے۔ اسی طرح انسانی ادراکات کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ان نعمتوں کی آخری حدود تک پہنچنا ممکن نہیں۔
وَ نَدَبَهُمْ لاِسْتِزادَتِها بِالشُّکْرِ لاِتِّصالِها،
نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کیلئے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت کی۔(۷)
وَ اسْتَحْمَدَ اِلَى الْخَلائِقِ بِاِجْزالِها، وَ ثَنی بِالنَّدْبِ اِلى اَمْثالِها.
حمد کا حکم اس لئے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو ایسی نعمتوں کی طرف مکرر دعوت دی (جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں)۔(۸)
وَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ،
اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔
کَلِمَةٌ جَعَلَ الْاِخْلاصَ تَأْویلَها،
(کلمہ شہادت) ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص (در عمل) کو اس کا نتیجہ قرارد یا ہے۔ (۹)
تشریح کلمات
اجزال:
فراوانی۔
ثنی، الثّٰنْی:
مکرر ۔
۷۔جیسا کہ قرآن میں فرمایا:
لئن شکرتم لازیدنکم (۱)
اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا
نعمتوں پر شکر کرنا اعلیٰ قدروں کا مالک ہونے کی دلیل ہے ایسے لوگ ہی نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں:
شکر النعمۃ اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الرجل: الحمد للّہ رب العالمین (ابراہیم؍ ۷)
حرام چیزوں سے اجتناب ہی نعمت کا شکر ہے اور شکر اس وقت پورا ہو جاتا ہے جب بندہ یہ کہدے: الحمدللہ رب العالمین۔
۸۔یعنی نیک اعمال کی دعوت دی تاکہ اس قسم کی نعمتیں آخرت میں بھی میسر آئیں۔
۹۔یعنی: ایک خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ دوسرے خود ساختہ خداؤں سے بے نیاز ہو کر صرف اس قادر لایزال کے ساتھ وابستہ ہو۔ توحید عقیدتی کا لازمی نتیجہ توحید عملی ہے اور عمل میں توحید پرست ہونے یعنی صرف اور خالصۃً اللہ تعالی پربھروسہ کرنے کی صورت میں مؤحد جبرائیل جیسے مقتدر فرشتہ کو بھی اعتنا میں نہیں لاتا۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ آتش نمرود میں جاتے وقت جبرئیل نے حضرت ابراہیم ؑسے کہا تھا کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا :
اما الیک فلا
آپ سے نہیں۔
وَ ضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها،
کلمۂ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزین فرمایا۔(۱۰)
وَ اَنارَ فِی التَّفَکُّرِ مَعْقُولَها،
اور اس کے ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی۔
الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْاَبْصارِ رُؤْیَتُهُ،
نہ وہ نگاہوں کی(محدودیت)میں آ سکتا ہے۔ (۱۱)
۱۰۔ماہرین نفسیات کی تحقیق میں یہ بات سامنے آگئی ہے :
’’معرفت الٰہی فطری ہے اس سے پہلے وہ ذوق جمالیات، انسان دوستی اور علم دوستی ہی کو فطری تصور کرتے تھے۔‘‘
اب معلوم ہو اہے کہ خدا پرستی ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں موجود ہے، البتہ خدا پرستی کے خلاف منفی اثرات کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں فطرت کے یہ تقاضے ابھر کر سامنے نہیں آتے، چنانچہ انسان دوستی ایک فطری امر ہونے کے باوجود بعض لوگوں پر منفی اثرات مترتب ہونے کی وجہ سے انسان دوستی کی جگہ وہ انسان دشمنی پر اتر آتے ہیں۔
۱۱۔اللہ تعالیٰ حاسہ بصر کی محدودیت میں نہیں آ سکتا بلکہ رؤیت خدا کا تصور ہی شان الٰہی میں گستاخی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالی علانیہ دکھانے کے مطالبے پر قوم موسیٰ پر عذاب نازل ہوا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اس طرح آیا ہے:
فقالوا ارنا اللہ جھرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم (نساء ؍۱۵۳)
انہوں نے کہا: ہمیں علانیہ طور پر اللہ دکھا دو ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔
وَ مِنَ الْاَلْسُنِ صِفَتُهُ،
اورنہ ہی زبان سے اس کا وصف بیان ہو سکتا ہے۔
وَ مِنَ الْاَوْهامِ کَیْفِیَّتُهُ.
اور وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔
اِبْتَدَعَ الْاَشْیاءَ لا مِنْ شَىْءٍ کانَ قَبْلَها،
ہر چیز کو لا شی ٔ سے وجود میں لایا (۱۲)
وَ اَنْشَاَها بِلاَاحْتِذاءِ اَمْثِلَةٍ اِمْتَثَلَها،
اور کسی نمونے کے بغیر ان کو ایجاد کیا۔
کَوَّنَها بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأَها بِمَشِیَّتِهِ،
اپنی قدرت سے انہیں وجود بخشا اور اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی۔(۱۳)
مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ مِنْهُ اِلى تَکْوینِها،
نہ ان کی ایجاد کی اسے ضرورت تھی۔
تشریح کلمات
الاحتذا:
پیروی کرنا۔
ذرأ:
خلق کرنا۔
۱۲۔ عدم سے وجود دینے کو خلق ابداعی کہتے ہیں اس معنی میں صرف اللہ تعالیٰ خالق ہے جبکہ اجزائے موجودہ کو ترکیب دینے کو بھی تخلیق کہا جاتا ہے، اس سے غیر اللہ بھی متصف ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ ؑ کے بارے میں ہے :
و اذ تخلق من الطین کھیئۃ الطیر باذنی۔ ( سورہ مائدہ؍۱۱۰)
اور میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا۔
۱۳۔ ان اشیاء کی ایجاد و تخلیق پر صرف اور صرف اللہ تعالی کی قدرت اور ارادہ صرف ہوا ہے۔ حتی کہ کاف و نون بھی خرچ نہیں ہوا بلکہ کن فیکون انسان کے فہم کے لیے صرف ایک تعبیر ہے۔
چنانچہ روایت میں آیا ہے:
فارادۃ اللہ الفعل لا غیر ذلک یقول لہ کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان (الکافی ۱؍۱۰۹)
ارادۂ خدا فعل خدا ہے جب وہ کن کہتا ہے وہ بغیر کسی لفظ اور زبانی نطق سے ہوتا ہے۔‘‘
وَ لا فائِدَةٍ لَهُ فی تَصْویرِها،
نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی مفاد تھا (۱۴)
اِلاَّ تَثْبیتاً لِحِکْمَتِهِ
وہ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا
وَ تَنْبیهاً عَلی طاعَتِهِ،
اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا
وَ اِظْهاراً لِقُدْرَتِهِ
اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا
وَ تَعَبُّداً لِبَرِیَّتِهِ،
اور مخلوق کو اپنی بندگی کے دائر میں لانا چاہتا تھا
وَ اِعْزازاً لِدَعْوَتِهِ،
اور اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا
ثُمَّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلی طاعَتِهِ، وَ وَضَعَ الْعِقابَ عَلی مَعْصِیَتِهِ،
پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا
ذِیادَةً لِعِبادِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ
تاکہ اس کے بندے اس کی غضب سے بچے رہیں۔
وَ حِیاشَةً لَهُمْ اِلى جَنَّتِهِ
اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں (۱۵)
تشریح کلمات
ذیادۃ:
ذود سے رفع کرنا، دور کرنا۔
حیاشۃ:
چلانا، گامزن کرنا۔
۱۴۔ اشیاء اپنی وجود اور اپنے بقا میں اللہ تعالی کی محتاج ہیں اللہ تعالی ان اشیاء کا محتاج نہیں ہے مگر ان اشیاء کو وجود دے کر اللہ اپنی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ ان مخلوقات کی خلقت کی غرض و غایت خود مخلوقات کی ارتقا ہے، چنانچہ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی بندگی انسانیت کیلئے معراج ہے کیونکہ بندگی کمال کے ادراک کا نتیجہ ہے اور کمال کا ادراک خود اپنی جگہ ایک کمال ہے لہذا اطاعت و بندگی انسان کے لئے ارتقا ء ہے۔
۱۵۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت وجود کے ساتھ بے شمار نعمتیں عنایت فرمائیں ہیں ہماری طرف سے اللہ کی اطاعت سے تو ان نعمتوں کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اطاعت پر ثواب بھی مرحمت فرماتا ہے اور اپنی جنت کی دائمی زندگی عنایت فرماتا ہے۔ یعنی دنیا کی چند روزہ اطاعت کے عوض ابدی ثواب عنایت فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں: اطاعت کے ایک لمحے کے مقابلے میں جنت میں ابدی زندگی عنایت فرماتا ہے۔
وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَبیمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،
اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر محمد اللہ کا عبد اور اس کے رسول ہیں،
اِخْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ،
اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا تھا
وَ سَمَّاهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ،
اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا۔ (۱۶)
تشریح کلمات
انتجبہ:
برگزیدہ کیا
اجتبلہ:
اس کو خلق کیا
۱۶۔ چنانچہ تغیر و تحریف کے باوجود آج بھی توریت و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں تصریحات موجود ہیں۔
توریت استثنا ۱۸۔۵۱ میں مذکور ہے:
’’ خداوندا ! تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھر یو‘‘۔
انجیل یوحنا میں آیا ہے:
’’اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار ’’فارقلیط‘‘ بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا‘‘۔
’’فارقلیط‘‘ یونانی لفظ ہے اس کا تلفظPARACLETEہے اس سے مراد ہے عزت یا مدد دینے والا اس کا دوسرا تلفظ ’’فیرقلیط‘‘ ہے اور یونانی تلفظ PERICLITEہے جس سے مراد عزت دینے والا بلند مرتبہ اور بزرگوار ہے جو محمد اور محمود کے قریب المعنی ہے۔
وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ،
اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا
اِذ الْخَلائِقُ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَةٌ،
جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں
وَ بِسَتْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ،
وحشت ناک تاریکی میں گم تھیں
وَ بِنِهایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ،
اور عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھیں۔
عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعالی بِمائِلِ الْاُمُورِ،
اللہ کو(اس وقت بھی)آنے والے امور پر آگہی تھی
وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّهُورِ،
اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعہ پر احاطہ تھا۔
وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ الْاُمُورِ
اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ (۱۷)
تشریح کلمات
مکنون:
پوشیدہ۔
مایل الامور :
انجام پانے والے امور۔
۱۷۔ اللہ کا علم معلوم کے وجود پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ معلومات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر احاطۂ علم رکھتا تھا۔ کیونکہ اللہ کے لئے بعد قبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے علم کے لئے زمانہ حائل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا علم زمانی نہیں ہے۔ اس کے علم کے لئے ماضی اور مستقبل یکساں ہے۔
چنانچہ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:
عالم اذلا معلوم و رب اذلا مربوب وقادر اذلا مقدور (نہج البلاغہ۹؍۱۴۷)
وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی معلوم موجود نہ تھا اور اس وقت بھی رب تھا جب کوئی مربوب نہ تھا، اور اس وقت بھی قادر تھا جب کوئی مقدور نہ تھا۔
اِبْتَعَثَهُ اللَّهُ اِتْماماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمَةً عَلى اِمْضاءِ حُکْمِهِ، وَ اِنْفاذاً لِمَقادیرِ رَحْمَتِهِ،
اللہ نے رسول کو اپنے امور کی تکمیل اور اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔(۱۸)
فَرَأَى الْاُمَمَ فِرَقاً فی اَدْیانِها،
رسول خداؐ نے اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں
عُکَّفاً عَلی نیرانِها،
کچھ اپنے آتشکدوں میں منہک
عابِدَةً لِاَوْثانِها،
اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف
مُنْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفانِها
معرفت کے باوجود اللہ کی منکر تھیں (۱۹)
تشریح کلمات
عکفا :
منہمک، ملتزم
اوثان:
وثن کی جمع ۔ بت
۱۸۔ حضرت رسالتمآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے امور الٰہی کی تکمیل ہوئی، احکام خداوندی کا نفاذ ہوا اور مقدرات حتمی کو عملی شکل مل گئی۔ اس کایہ واضح مطلب ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مظہر تکمیل امر الہٰی ہیں وہ مظہر ارادۂ خداوندی ہے انہیں کے ذریعہ مقدرات الہٰی مرحلہ علم سے مرحلہ وجود میں آتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:
لولاک لما خلقت الافلاک (بحار الانوار ۱۵؍۲۷)
اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو بھی خلق نہ کرتا۔
۱۹۔چنانچہ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ؑ اسی مطلب کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:
واہل الارض یومئذ ملل متفرقۃ واھواء منتشرۃ و طرائق متشتتہ، بین مشبہ للّہ بخلقہ او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیرہ فھدیھم من الضلالۃ و انقذہم بمکانہ من الجھالۃ۔ (نہج البلاغہ)
اس وقت کرۂ ارض کے باشندے متفرق قوموں میں بٹے ہوئے تھے منتشر خیالات اور مختلف راہوں میں سرگرداں تھے کچھ اللہ کو مخلوق کے مانند سمجھتے تھے کچھ ملحد ومنکر تھے اور کچھ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ایسے حالات میں اللہ نے محمدؐ کے ذریعہ ان کو گمراہی سے ہدایت بخشی اور ان کے ذریعہ انہیں جہالت سے بچا لیا۔
فَاَنارَ اللَّهُ بِاَبیمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ ظُلَمَها،
پس اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی محمدؐ کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا
وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَها،
اور دلوں سے ابہام کو
وَ جَلى عَنِ الْاَبْصارِ غُمَمَها،
اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کر دیا
وَ قامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدایَةِ،
(میرے والدنے) لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا
فَاَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوایَةِ،
اور انہیں گمراہوں سے نجات دلائی۔
وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمایَةِ،
آپ انہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے
وَ هَداهُمْ اِلَى الدّینِ الْقَویمِ،
نیز آپ نے استواردین کی طرف ان کی راہنمائی کی۔
وَ دَعاهُمْ اِلَى الطَّریقِ الْمُسْتَقیمِ
راہ راست کی طرف انہیں دعوت دی
ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ
پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا
قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیارٍ،
شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ
وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ،
نیز(آخرت کی) ترغیب و ترجیح کے ساتھ۔(۱۹)
تشریح کلمات
بُھْم :
ابہام
غُمَم :
حیرانی، راہ نہ پانا۔
۱۹۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے از راہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے وصال کو اختیار فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کو اختیار فرمایا ہو، چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عزرائیل کسی کی روح قبض کرنے کے لئے اجازت نہیں مانگتے لیکن صرف رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے موقع پر آپ سے اجازت طلب کی اور حضورؐ کی اجازت سے قبض روح عمل میں آیا۔